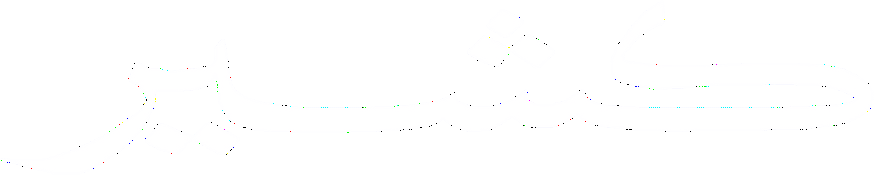شہری کا لہو اور لیڈر کا پسینہ
ڈینیئل شیکٹر ہارورڈ یونیوسٹی میں نفسیات کے استاد ہیں۔ 1952 میں پیدا ہونے والے پروفیسر شیکٹر کی تحقیق کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ افرادی اور اجتماعی یاد داشت متعدد عوامل کے زیر اثر اصل واقعات کو از سرِنو مرتب کر لیتی ہے۔ فرد لاشعوری طور پر اپنی عزتِ نفس کی نفی اور احترام ذات کی جسمانی شکست کے بہت سے پہلو فراموشی کے تاریک حجرے میں بند کر کے انہیں کسی قدر قابلِ قبول بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ گروہی سطح پر اسی عمل میں مرتب منصوبہ بندی، تاریخی واقعات کی من مانی تشریح، اجتماعی پس اندیشی، مسخ شدہ معلومات، نصابی تلقین اور ریاستی بیانیے جیسے اوزاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ اس موضوع پر پروفیسر شیکٹر کی تحقیق کا نچوڑ ان کی کتاب The Seven Sins of Memory (2001) میں دیکھا جا سکتا ہے اور اگر اس نظریے کا سیاسی اطلاق سمجھنا ہو تو ہم عصر ماہرین نفسیات کے مجموعۂ مضامینMemory distortion: how minds, brains, and societies reconstruct the past سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ قصے تو نفسیات کی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں سائنس کے بے رحم حقائق سے کیا تعلق؟ یہ معاملات رفیق جعفر، آثر اجمل اور اختر علی سید بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم سادہ دل تو تاریخ کے پاپیادہ قافلے کا غبار ہیں۔ ہمارے لیے لوح ادب پر کندہ اس حرف تازہ کی شہادت کافی ہے جس سے ٹپکتے لہو کے قطرے خشک نہیں ہوتے۔ ہمارے عہد کے ایک بڑے ادیب میلان کنڈیرا نے لکھا: The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting ۔ اب کنڈیرا کی بات کو پروفیسر شیکٹر کی رائے سے جوڑ کر دیکھیے، گویا اجتماعی سطح پر یاد داشت کی تنسیخ، فراموشی کی روایت اور حقائق کی ترتیب نو محض لاشعوری محرکات کا کرشمہ نہیں ہیں، یہ اجارے اور محرومی، ظلم اور انصاف نیز تشدد اور امن کی لامتناہی کشمکش ہے۔
لمحہ موجود میں بلوچستان اور سندھ کے گم شدہ سیاسی کارکنوں کا نام لینا تو خیر صاحبانِ اختیار کے حساس اعصاب میں سوئی چبھونے کے مترادف ہے۔ (گستاخی معاف، ایک جمہوری ریاست میں شہری یا تو آزاد ہوتا ہے یا قانون کی باضابطہ تحویل میں ہوتا ہے یا مغوی ہونے کی صورت میں حبس بے جا کے قانون کے تحت اس کی بازیابی ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ گم شدہ کی اصطلاح اگر بوجوہ ناقابلِ فہم نہیں تو پھر ریاستی جرم کے ذیل میں آتی ہے) ابھی تو ہم نے 71ء کی ابتلا پر ہم وطن صحافی انتھونی میکارنیس(Anthony Mascarenhas) ، بیورو کریٹ حسن ظہیر، بریگیڈیئر صدیق سالک، میجر جنرل خادم حسین راجا اور میجر جنرل حکیم ارشد قریشی جیسے محبانِ وطن کی تصانیف کو اپنے اجتماعی مکالمے کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دی۔ قلی کیمپ کوئٹہ، شاہی قلعہ لاہور، دلائی کیمپ، قلعہ بالاحصار، اٹک قلعہ اور نیپیئر بیرکس کراچی کے عقوبت خانوں کی مبسوط روداد ابھی قلم بند نہیں ہو سکی۔ بریگیڈیئر امتیاز بلا، لیفٹیننٹ جنرل (ر) ندیم تاج اور راﺅ انوار جیسے کرداروں کے ہوتے ہوئے اس کی توقع بھی نہیں۔ عام شہری کی بے بسی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تو بظاہر طاقتور کردار بھی آزمائش پڑنے پر قانون اور لاقانویت کے دو پاٹوں میں پس جاتے ہیں تو پھر ریاستی جبر کو سمجھنے کے لیے وہی آزمودہ نسخہ آزماتے ہیں، یعنی اپنے وطن سے چشم پوشی کرتے ہوئے کسی دور دراز دیس کے قصے بیان کرتے ہیں۔ پڑھنے والا ہم ایسے ناکردہ کار لکھنے والوں سے کہیں زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ درست نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
قلمروئے روس میں ایک شاعرہ گزری ہیں، انا اخماتوا۔ انقلاب روس برپا ہوا تو بمشکل 28 برس کی رہی ہوں گی۔ اگلی نصف صدی اسی آزمائش میں گزری۔ شاعر کی مجبوری ہے، شاعر ٹیلی ویژن پر قومی موضوعات پر ڈرامے اور سرکاری مجلے میں ہدایت یافتہ مضامین نہیں لکھ سکتا۔ شعر ایک چلبلا بچہ ہے۔ شاعر معروضی بدنمائی کو سمجھ کر شعر کو خاموش کرنے کے لیے زوردار چانٹا رسید کرتا ہے مگر ادھر آنکھ بچی، ادھر شعر کی معصومیت لوٹ آتی ہے۔ بچے کی ہنسی اور شعر کی سچائی موقع شناس نہیں ہوتی۔ انا اخماتوا پر پوری نظر رکھی گئی تھی لیکن اس نے شعر کہنا ترک کیا اور نہ جلاوطنی اختیار کی۔ تلوار کی دھار پر اس سفر میں انا اخماتوا کی معروف ترین کتاب کا عنوان ہے The Word That Causes Death’s Defeat۔اس کتاب کی معروف ترین نظم 1957 میں ’نوحہ‘ کے عنوان سے لکھی گئی تھی۔ اس نظم میں ایک مختصر سا پیش لفظ بھی شامل ہے جو 1930 کی دہائی کے آخری برسوں میں NKVD کے سربراہ نکولائی یازوف کی سربراہی میں ’عہدِ دہشت ‘کا مختصر ترین بیان ہے۔ واضح رہے کہ 1940 میں خود نکولائی یازوف کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو وہ گھٹنوں کے بل جھک کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نکولائی یازوف کے جانشین لیورینٹائی بیریا کو دسمبر 1953 میں سزائے موت دی گئی تو وہ بھی ٹھیک اسی انداز میں رحم کی درخواست کر رہا تھا۔ آمریت کا حقیقی المیہ یہی ہے کہ دوسروں کی موت کے پروانے جاری کرنے والے ایک روز خود بھی اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ آمریت اپنے پالے ہوئے کوبرے کو کیچوے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔
انا اخماتوا کی طرف واپس چلتے ہیں۔ 1938 کے برس میں شاعرہ لینن گراڈ میں 37 ماہ تک ریاستی عقوبت خانے کے پہلو میں قیام پذیر تھی۔ ایک روز کسی عورت نے اسے پہچان لیا اور سرگوشی میں سوال کیا ۔’کیا تم اسے بیان کر سکتی ہو‘۔ شاعرہ نے آنکھ اٹھا کر اس عورت کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دہشت کی تصویر بن چکا تھا اور آہستہ سے جواب دیا ۔ ’ہاں میں اسے بیان کروں گی‘۔ اور پھر یہ بیان نوحہ کے عنوان سے ایک طویل نظم میں ڈھل گیا۔ چند سطریں ملاحظہ ہوں۔
A grief so great would lay a mountain low,
Would make the rush of mighty rivers cease,
But has no power to move the prison bolts
Or reach beyond them to the ‘‘convicts’ holes
And the mortal agony ’’
یہ سو برس پہلے کے قصے ہیں۔ آج ہٹلر کا آسوٹز یا بوخن والڈ باقی ہیں اور نہ اسٹالن کے گولاگ، مگر سوڈان سے سنکیانگ تک اور سری نگر سے غزہ کی پٹی تک انسان کی تقدیر نہیں بدلی اور کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جنہیں دوستوفسکی اور اس کے ساتھیوں سمیت پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سماعت کی تاریخ مقرر ہوتی ہے مگر فیصلہ تعویق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ 23 کروڑ افراد کی زندگیاں بیان کرنے کے لیے فیض کی شاعری میں بہت سے حوالے موجود ہیں مگر انااخماتوا ہی سے گواہی لیتے ہیں۔
But among my people, I took up my place,
There, where by an ill fate, my own people were.
لیڈر کے عرق انفعال کی پکار پر ’زمان پارک چلو‘ کا نعرہ بلند کرنے والوں کو شاید علم نہ ہو کہ لاکھوں گھروں کے چولہے اس سازش کے نتیجے میں بجھ چکے ہیں جسے شجاع پاشا سے لے کر فیض حمید تک ’وطن پرستوں‘ کی ایک پوری کھیپ نے مرتب کیا۔ عوام کو آٹے دال کا بھاﺅ معلوم ہو گیا ہے لیکن سیاسی مکالمے میں معیشت کا کوئی ذکر نہیں۔ ذرائع ابلاغ کا موضوع پارلیمنٹ اور عدلیہ میں آنکھ مچولی ہے اور قوم کی مائیں چولہے پر رکھی ہنڈیا میں امید کی کنکریاں ہلا رہی ہیں۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں میں امید کے دو دھاری خنجر کی نوک پر خاموش بیٹھے کروڑوں بچے آنے والے کل میں جوان ہوں گے تو خالی ہاتھ گھر لوٹنے والے بوڑھے باپ کے پسینے میں غافل رہنما کی رگوں میں دوڑتے لہو کو پہچان لیں گے۔ اس سے پہلے کہ نمائندگان کا ایوان اپنی قرارداد پاس کرے اور عدالت اپنا فیصلہ دے، ایک نظر اُجڑے ہوئے بازار اور بند کارخانے پر ڈال لینی چاہیے۔ ممکن ہو تو جان لینا چاہیے کہ درآمدات پر بندش عائد کر کے تجارت کا خسارہ کم نہیں ہوتا۔ ہم عوام کے لہو اور لیڈر کے پسینے میں جو تقابل کر رہے ہیں اس میں قومی نجات کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ ماضی کی غلطیوں کو تاریخ کی کتاب میں فراموشی اور حسبِ منشا تشریح کے سپرد کا جا سکتا ہے لیکن آج کی اداسی ایک کوہِ گراں کی طرح حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہے۔ فیض کی دعا ہی سے رجوع کرتے ہیں:
وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں
ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے
بشکریہ ہم سب
واپس کریں
لمحہ موجود میں بلوچستان اور سندھ کے گم شدہ سیاسی کارکنوں کا نام لینا تو خیر صاحبانِ اختیار کے حساس اعصاب میں سوئی چبھونے کے مترادف ہے۔ (گستاخی معاف، ایک جمہوری ریاست میں شہری یا تو آزاد ہوتا ہے یا قانون کی باضابطہ تحویل میں ہوتا ہے یا مغوی ہونے کی صورت میں حبس بے جا کے قانون کے تحت اس کی بازیابی ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ گم شدہ کی اصطلاح اگر بوجوہ ناقابلِ فہم نہیں تو پھر ریاستی جرم کے ذیل میں آتی ہے) ابھی تو ہم نے 71ء کی ابتلا پر ہم وطن صحافی انتھونی میکارنیس(Anthony Mascarenhas) ، بیورو کریٹ حسن ظہیر، بریگیڈیئر صدیق سالک، میجر جنرل خادم حسین راجا اور میجر جنرل حکیم ارشد قریشی جیسے محبانِ وطن کی تصانیف کو اپنے اجتماعی مکالمے کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دی۔ قلی کیمپ کوئٹہ، شاہی قلعہ لاہور، دلائی کیمپ، قلعہ بالاحصار، اٹک قلعہ اور نیپیئر بیرکس کراچی کے عقوبت خانوں کی مبسوط روداد ابھی قلم بند نہیں ہو سکی۔ بریگیڈیئر امتیاز بلا، لیفٹیننٹ جنرل (ر) ندیم تاج اور راﺅ انوار جیسے کرداروں کے ہوتے ہوئے اس کی توقع بھی نہیں۔ عام شہری کی بے بسی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تو بظاہر طاقتور کردار بھی آزمائش پڑنے پر قانون اور لاقانویت کے دو پاٹوں میں پس جاتے ہیں تو پھر ریاستی جبر کو سمجھنے کے لیے وہی آزمودہ نسخہ آزماتے ہیں، یعنی اپنے وطن سے چشم پوشی کرتے ہوئے کسی دور دراز دیس کے قصے بیان کرتے ہیں۔ پڑھنے والا ہم ایسے ناکردہ کار لکھنے والوں سے کہیں زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ درست نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
قلمروئے روس میں ایک شاعرہ گزری ہیں، انا اخماتوا۔ انقلاب روس برپا ہوا تو بمشکل 28 برس کی رہی ہوں گی۔ اگلی نصف صدی اسی آزمائش میں گزری۔ شاعر کی مجبوری ہے، شاعر ٹیلی ویژن پر قومی موضوعات پر ڈرامے اور سرکاری مجلے میں ہدایت یافتہ مضامین نہیں لکھ سکتا۔ شعر ایک چلبلا بچہ ہے۔ شاعر معروضی بدنمائی کو سمجھ کر شعر کو خاموش کرنے کے لیے زوردار چانٹا رسید کرتا ہے مگر ادھر آنکھ بچی، ادھر شعر کی معصومیت لوٹ آتی ہے۔ بچے کی ہنسی اور شعر کی سچائی موقع شناس نہیں ہوتی۔ انا اخماتوا پر پوری نظر رکھی گئی تھی لیکن اس نے شعر کہنا ترک کیا اور نہ جلاوطنی اختیار کی۔ تلوار کی دھار پر اس سفر میں انا اخماتوا کی معروف ترین کتاب کا عنوان ہے The Word That Causes Death’s Defeat۔اس کتاب کی معروف ترین نظم 1957 میں ’نوحہ‘ کے عنوان سے لکھی گئی تھی۔ اس نظم میں ایک مختصر سا پیش لفظ بھی شامل ہے جو 1930 کی دہائی کے آخری برسوں میں NKVD کے سربراہ نکولائی یازوف کی سربراہی میں ’عہدِ دہشت ‘کا مختصر ترین بیان ہے۔ واضح رہے کہ 1940 میں خود نکولائی یازوف کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو وہ گھٹنوں کے بل جھک کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نکولائی یازوف کے جانشین لیورینٹائی بیریا کو دسمبر 1953 میں سزائے موت دی گئی تو وہ بھی ٹھیک اسی انداز میں رحم کی درخواست کر رہا تھا۔ آمریت کا حقیقی المیہ یہی ہے کہ دوسروں کی موت کے پروانے جاری کرنے والے ایک روز خود بھی اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ آمریت اپنے پالے ہوئے کوبرے کو کیچوے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔
انا اخماتوا کی طرف واپس چلتے ہیں۔ 1938 کے برس میں شاعرہ لینن گراڈ میں 37 ماہ تک ریاستی عقوبت خانے کے پہلو میں قیام پذیر تھی۔ ایک روز کسی عورت نے اسے پہچان لیا اور سرگوشی میں سوال کیا ۔’کیا تم اسے بیان کر سکتی ہو‘۔ شاعرہ نے آنکھ اٹھا کر اس عورت کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دہشت کی تصویر بن چکا تھا اور آہستہ سے جواب دیا ۔ ’ہاں میں اسے بیان کروں گی‘۔ اور پھر یہ بیان نوحہ کے عنوان سے ایک طویل نظم میں ڈھل گیا۔ چند سطریں ملاحظہ ہوں۔
A grief so great would lay a mountain low,
Would make the rush of mighty rivers cease,
But has no power to move the prison bolts
Or reach beyond them to the ‘‘convicts’ holes
And the mortal agony ’’
یہ سو برس پہلے کے قصے ہیں۔ آج ہٹلر کا آسوٹز یا بوخن والڈ باقی ہیں اور نہ اسٹالن کے گولاگ، مگر سوڈان سے سنکیانگ تک اور سری نگر سے غزہ کی پٹی تک انسان کی تقدیر نہیں بدلی اور کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جنہیں دوستوفسکی اور اس کے ساتھیوں سمیت پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سماعت کی تاریخ مقرر ہوتی ہے مگر فیصلہ تعویق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ 23 کروڑ افراد کی زندگیاں بیان کرنے کے لیے فیض کی شاعری میں بہت سے حوالے موجود ہیں مگر انااخماتوا ہی سے گواہی لیتے ہیں۔
But among my people, I took up my place,
There, where by an ill fate, my own people were.
لیڈر کے عرق انفعال کی پکار پر ’زمان پارک چلو‘ کا نعرہ بلند کرنے والوں کو شاید علم نہ ہو کہ لاکھوں گھروں کے چولہے اس سازش کے نتیجے میں بجھ چکے ہیں جسے شجاع پاشا سے لے کر فیض حمید تک ’وطن پرستوں‘ کی ایک پوری کھیپ نے مرتب کیا۔ عوام کو آٹے دال کا بھاﺅ معلوم ہو گیا ہے لیکن سیاسی مکالمے میں معیشت کا کوئی ذکر نہیں۔ ذرائع ابلاغ کا موضوع پارلیمنٹ اور عدلیہ میں آنکھ مچولی ہے اور قوم کی مائیں چولہے پر رکھی ہنڈیا میں امید کی کنکریاں ہلا رہی ہیں۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں میں امید کے دو دھاری خنجر کی نوک پر خاموش بیٹھے کروڑوں بچے آنے والے کل میں جوان ہوں گے تو خالی ہاتھ گھر لوٹنے والے بوڑھے باپ کے پسینے میں غافل رہنما کی رگوں میں دوڑتے لہو کو پہچان لیں گے۔ اس سے پہلے کہ نمائندگان کا ایوان اپنی قرارداد پاس کرے اور عدالت اپنا فیصلہ دے، ایک نظر اُجڑے ہوئے بازار اور بند کارخانے پر ڈال لینی چاہیے۔ ممکن ہو تو جان لینا چاہیے کہ درآمدات پر بندش عائد کر کے تجارت کا خسارہ کم نہیں ہوتا۔ ہم عوام کے لہو اور لیڈر کے پسینے میں جو تقابل کر رہے ہیں اس میں قومی نجات کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ ماضی کی غلطیوں کو تاریخ کی کتاب میں فراموشی اور حسبِ منشا تشریح کے سپرد کا جا سکتا ہے لیکن آج کی اداسی ایک کوہِ گراں کی طرح حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہے۔ فیض کی دعا ہی سے رجوع کرتے ہیں:
وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں
ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے
بشکریہ ہم سب
واپس کریں
وجاہت مسعود کے دیگرکالم اور مضامین